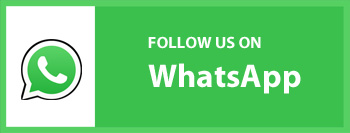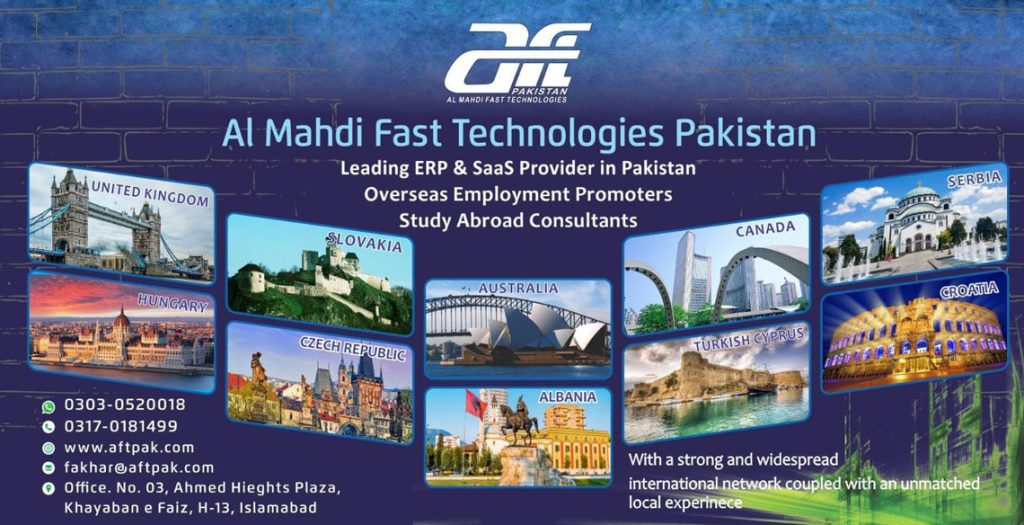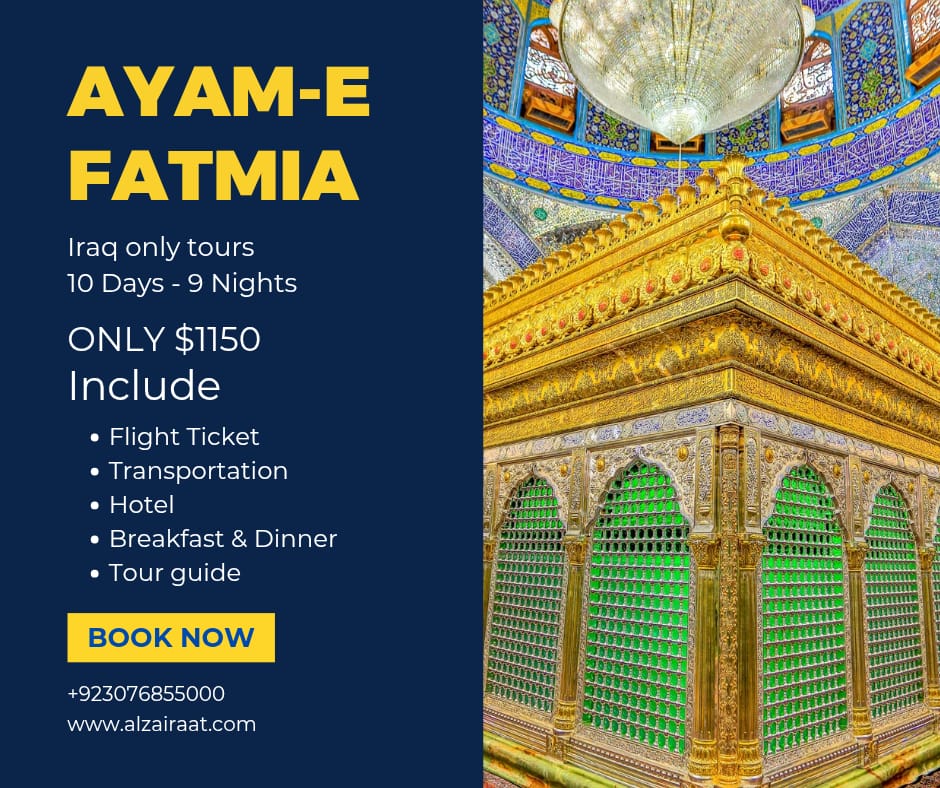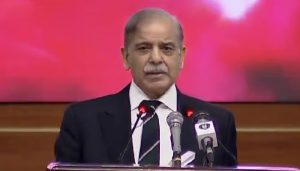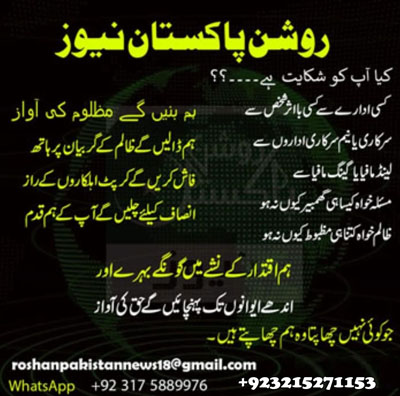ابتداً یہ کہنا ضروری ہے کہ طالبان اور پاکستان دونوں اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پر وہ اپنے مفادات کے لیے سوار ہیں۔ دنیا میں پاکستان کے سوا کم ہی کوئی ریاست یا معاشرہ طالبان کو سمجھتا یا تسلیم کرتا ہے، اور یہی تنہائی بین الاقوامی سطح پر ان کے لیے سنگین نتائج لے آئے گی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ طالبان کا وجود محض علاقائی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر سیاسی اثرات رکھتا ہے۔
پس منظر یہ ہے کہ طالبان دراصل پاکستانی سوچ اور مخصوص معاشرتی ڈھانچے کا عکس ہیں۔ پاکستان نے انہیں اس مقصد کے لیے پروان چڑھایا کہ افغانستان میں ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جو کچھ فوجی اور مذہبی حلقوں کے مفادات سے ہم آہنگ ہو؛ یہ منصوبہ علاقائی حکمتِ عملی کا حصہ رہا ہے۔ اس نقطۂ آغاز کا تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ پالیسیاں وقتی مفاد میں طویل المدت خطرات پیدا کر سکتی ہیں۔
اگلے پہلو پر غور کریں تو آج طالبان اور پاکستان کے درمیان ٹکراؤ ایک نئی حقیقت بن چکا ہے۔ بظاہر فتح پاکستان کی نظر آتی ہے، مگر اس فتح کے بعد افغانستان میں جو سیاسی خلاء پیدا ہوگا اس میں زیادہ پاکستان مخالف قوتیں پروان چڑھ سکتی ہیں۔ اسی عدم استحکام سے سرحد پار سیکورٹی اور اقتصادی چیلنجز جنم لیں گے۔
اس کے نتیجے میں یہ قابلِ غور ہے کہ پاکستان کی سرپرستی کھونے سے طالبان بھی بین الاقوامی اور اندرونی طور پر تنہا ہو جائیں گے۔ افغانستان کے اندر طالبان کی مقبولیت محدود رہنے کی وجہ سے انہیں مقامی مزاحمت کا سامنا ہے، اور بیرونی سہارا ختم ہونے پر انہی مسائل میں اضافہ ہوگا۔ اس سے خطے میں نئی سیاسی ترتیب کے امکانات بڑھتے ہیں۔
یہ امر قابلِ بحث نہیں کہ پائیدار امن کے بغیر معاشی ترقی اور خوشحالی محال ہیں۔ پاکستان میں بعض سیاسی شخصیات نے کھل کر کہا ہے کہ افغان جہاد نے ملک کو نقصان پہنچایا — یہ اعتراف ایک تاریخی احتساب کی طرف اشارہ ہے۔ ایسی بیانیہ تبدیلیاں عوامی شعور میں تبدیلی کے دروازے کھول سکتی ہیں۔
تاریخی پس منظر میں خواجہ محمد آصف کی ہمت نمایاں ہے جنہوں نے افغان جہاد کو پاکستان کی تباہی کا سبب قرار دیا۔ خواجہ آصف نے اپنے والد کے ماضی کو غلط کہہ کر ایک اخلاقی موقف اپنایا، جو کہ بحث و تمحیص کے قابل عمل ہے۔ اس طرح کے بیانات قومی مکالمے میں شفافیت کو فروغ دیتے ہیں۔
اس حقیقت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں موجود انتہا پسندی اور دہشت گردی کا ذمہ دار صرف طالبان نہیں۔ دیگر اندرونی مذہبی رجحانات اور نظریات نے بھی اس ماحول کو قابلِ برداشت بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلے کا حل صرف سکیورٹی اقدامات تک محدود نہیں ہو سکتا۔
مزید برآں کہا جانا چاہیے کہ 1980ء کے بعد پاکستان ایک طرح کی ’ذہنی فیکٹری‘ رہا ہے جو جہادی اور قدامت پسند ذہنیت تیار کرتی آئی ہے۔ اگرچہ اس کا آغاز پیچیدہ سیاسی حالات کا نتیجہ تھا، پھر بھی اس کی پیداواری روش نے ملکی سوسائٹی پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اس تاریخ کا ادراک اصلاح کے راستے کے لیے ضروری ہے۔
موجودہ فوجی و سیاسی رویوں کی بدولت مذہب کو بطورِ سیاسی ہتھیار استعمال کرنے کے آثار نظر آتے ہیں، اور اس کے منفی اثرات عوامی سطح تک پھیل چکے ہیں۔ اس عمل نے متنوع سیاسی و مذہبی رجحانات کو ایک مخصوص زاویے سے دیکھنے کا کلچر جنم دیا۔ اس کا ازالہ ایک جامع حکمتِ عملی مانگتا ہے۔
ان تجربات کے نتیجے میں آج ایک بڑی پرتِ معاشرہ طالبان والی سوچ کی حامل دکھائی دیتی ہے؛ یہاں تک کہ بعض اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد بھی اس رجحان سے متاثر ہیں۔ یہ امر بتاتا ہے کہ مسئلہ تعلیمی اور فکری سطح پر بھی موجود ہے — اس لیے نصاب اور تعلیمی معیار میں اصلاحات ضروری ہیں۔
اسی تناظر میں یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ اقلیتوں کے خلاف تشدد اور غیرانسانی سلوک بعض حلقوں میں نیکی اور ثواب کا درجہ پاتا ہے۔ یہ ذہنیت معاشرتی سالمیت کے لیے زہریلے اثرات رکھتی ہے اور اس کا سدِ باب سماجی و قانونی اصلاحات کے بغیر ممکن نہیں۔ ایسے رویوں سے نمٹنے کے لیے قانون اور معاشرتی بیداری مل کر کام کریں۔
مزید ایک قابلِ توجہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں شیعہ روایات اور قدامت پسندی کی مخصوص شکلیں ہیں جو دوسرے شیعہ معاشروں سے مختلف ہیں؛ یہ فرق تاریخی اور ثقافتی جڑوں کا نتیجہ ہے۔ اس تہذیبی تفاوت کا مطالعہ پالیسی سازوں کے لیے رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔
قانونی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو توہین مذہب کے سخت قوانین اور ان کے نفاذ نے معاشرتی کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ یہ قوانین تاریخی پس منظر رکھتے ہیں، مگر اب ان کا ازسرِ نو جائزہ لینا ملکی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے۔ قانون میں توازن لانا جمہوری و انسانی حقوق کے تقاضوں کا حصہ ہونا چاہیے۔
حالیہ بعض اقدامات اور امداد کی مثالیں بتاتی ہیں کہ ریاستی سطح پر بعض مدارس اور اداروں کی مدد پر سوالات اٹھتے ہیں، خاص طور پر جب وہ انتہا پسندی کے پھیلاؤ میں کردار رکھتے ہوں۔ اس قسم کی معاونت پر شفافیت اور معیاری جانچ ضروری ہے تاکہ ایسی پالیسیوں کے منفی اثرات کم ہوں۔
اسی پس منظر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار اہم بن کر سامنے آتا ہے؛ ان کے پاس عربی زبان و شریعت کی سمجھ، فوجی اختیار اور بین الاقوامی روابط موجود ہیں جو انتہا پسندی کے خاتمے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ مگر ان کے اقدامات کو کامیاب بنانے کے لیے عسکری طاقت کے ساتھ ساتھ سول اصلاحات، تعلیمی پالیسی اور عوامی حمایت درکار ہوگی۔
اگر عوام اور ریاست دونوں فیلڈ مارشل کی نیت اور اخلاص پر یقین کر لیں تو وہ مذہبی دہشت گردی کے خلاف کامیاب مہم میں ساتھ دیں گے۔ تاہم یہ ایک خطرناک، طولانی اور اجتماعی عمل ہے۔ اس میں صرف سکیورٹی فورسز کا زور کافی نہیں؛ سماجی، تعلیمی اور اقتصادی اصلاحات لازمی ہیں۔
آخری لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریاستی طاقت اور عوامی تعاون مل کر عارضی کامیابیاں دلوا سکتے ہیں، مگر مستقل امن کے لیے تعلیمی نظام، تربیت اور ثقافتی شناخت کی ازسر نو تشکیل ناگزیر ہے۔ اسی صورت میں پاکستان ایک پرامن، مستحکم اور قابلِ تقلید معاشرہ بن سکتا ہے۔